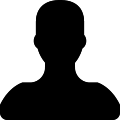پینتیس سالہ حلیمہ باجوڑ کی تحصیل اتمانخیل کے ایک گاؤں کی رہائشی ہیں جو اپنے چھ بچوں سمیت گھر کے دس افراد کا کھانا تیار کر رہی ہیں۔ اگرچہ بچے ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تاہم اتنے لوگوں کا روزانہ دو وقت کھانا بنانا آسان نہیں ہوتا۔
وہ بتاتی ہیں کہ چند سال پہلے تک وہ لکڑیوں پر کھانا بناتی تھیں۔ سالن اور چائے بنانا تو بڑا مسئلہ نہیں تھا، روٹی تندور پر پکانی ہوتی تھی جس کو گرم کرنے کے لیے بہت ساری لکڑیاں ڈالنا پڑتی تھیں۔ پہاڑوں پر جا کر لکڑیاں جمع کرنا اور انہیں گھر لانا زیادہ مشکل ہوتا تھا "
"سردیوں میں ہماری مشکلات مزید بڑھ جاتی تھیں کیونکہ مسلسل بارشوں سے خشک لکڑیاں کم پڑ جاتی تھیں۔ دن رات یہی فکر ہوتی کہ کھانا وقت پر نہ بنا تو کیا ہوگا؟ کئی بار گھر والوں کی باتیں سننا پڑتی تھیں۔"
حلیمہ اپنے بازو پر جلن کا نشان دکھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ 13 سال پہلے تندور میں روٹی لگاتے ہوئے جھلس گیا تھا۔ ہاتھ تو اکثر جل جاتے تھے، تندور کا دھواں اتنا تیز ہوتا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔
"ہمیں دو چار منٹ تاخیر ہو جاتی یا روٹیاں زیادہ لگانی ہوتیں تو تندور کی تپش کم ہو جاتی اور اسے دوبارہ گرم کرنا پڑتا تھا۔"
تاہم اب وہ بائیو گیس پر کھانا بنا رہی ہیں، کہتی ہیں کہ شکر ہے حکومت کو خواتین کا بھی خیال آیا جس نے یہاں بائیو گیس کا پلانٹ لگا کر دیا ہے۔ تب سے ان کی لکڑیاں جمع کرنے، تپش اور دھوئیں کے عذاب سے جان چھوٹ گئی ہے۔
ایسے ہی بائیو گیس پلانٹس نے ناصرف حلیمہ بلکہ قبائلی اضلاع میں سیکڑوں خواتین کی مشکل آسان کردی ہے۔ تاہم ابھی تک لاکھوں گھرانے معلومات کی کمی یا دیگر وجوہات کے باعث لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں۔

لاکھوں ٹن لکڑی کا بطور ایندھن استعمال درختوں اور ماحولیات کی تباہی
محکمہ شماریات کا 2023ء کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ خیبرپختونخوا کے تقریباً 58 لاکھ 61 ہزار گھروں میں سے 41 لاکھ 84 ہزار اب بھی لکڑی پر کھانا پکاتے ہیں۔ 13لاکھ 22 ہزار گھرانے کھانا بنانے کے لیے قدرتی گیس، ایک لاکھ 70 ہزار سلنڈر اور ایک لاکھ 85 ہزار دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں۔
پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ اکنامکس (پائیڈ) اور کامسیٹس اسلام آباد کی مشترکہ سٹڈی رپورٹ کے مطابق ملک کے ایک اوسط گھرانے نے 19-2018ء میں سالانہ اوسطاً ایک ہزار 706 کلو گرام لکڑی استعمال کی جس سے 19.29 گیگا گرام کاربن کا اخراج ہوتا ہے۔
واضح رہے یو این ڈی پی نے پاکستان میں 1991ء میں فی گھرانہ لکڑی کے سالانہ استعمال کا اندازہ دو ہزار 324 کلو گرام لگایا تھا۔
اگر تازہ ترین رپورٹ پر بھروسہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبرپختونخوا میں 41 لاکھ 84 ہزار کنبے کھانا بنانے اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے سالانہ لگ بھگ 71لاکھ 38 ہزار ٹن لکڑی جلاتے ہیں۔
یعنی صوبے میں گھریلو ایندھن کےلیے ہر سال لاکھوں درخت کاٹے جاتے ہیں جس سے ناصرف ماحول تباہ ہو رہا ہے بلکہ اس ایندھن کے جلنے سے ٹنوں کے حساب سے کاربن بھی خارج ہوتی ہے جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہے۔
ضلع باجوڑ کی 12 لاکھ 88 ہزار آبادی مجموعی طور پر ایک لاکھ 81ہزار 699 گھرانوں پر مشتمل ہے جن میں سے ایک لاکھ 54 ہزار 436 گھروں میں اب بھی لکڑی پر کھانا بنتاہے۔ ایک ہزار 348 خاندان قدرتی گیس، 786 سلنڈر اور باقی 25 ہزار کنبے مٹی کا تیل، بجلی، بائیو گیس وغیرہ بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔
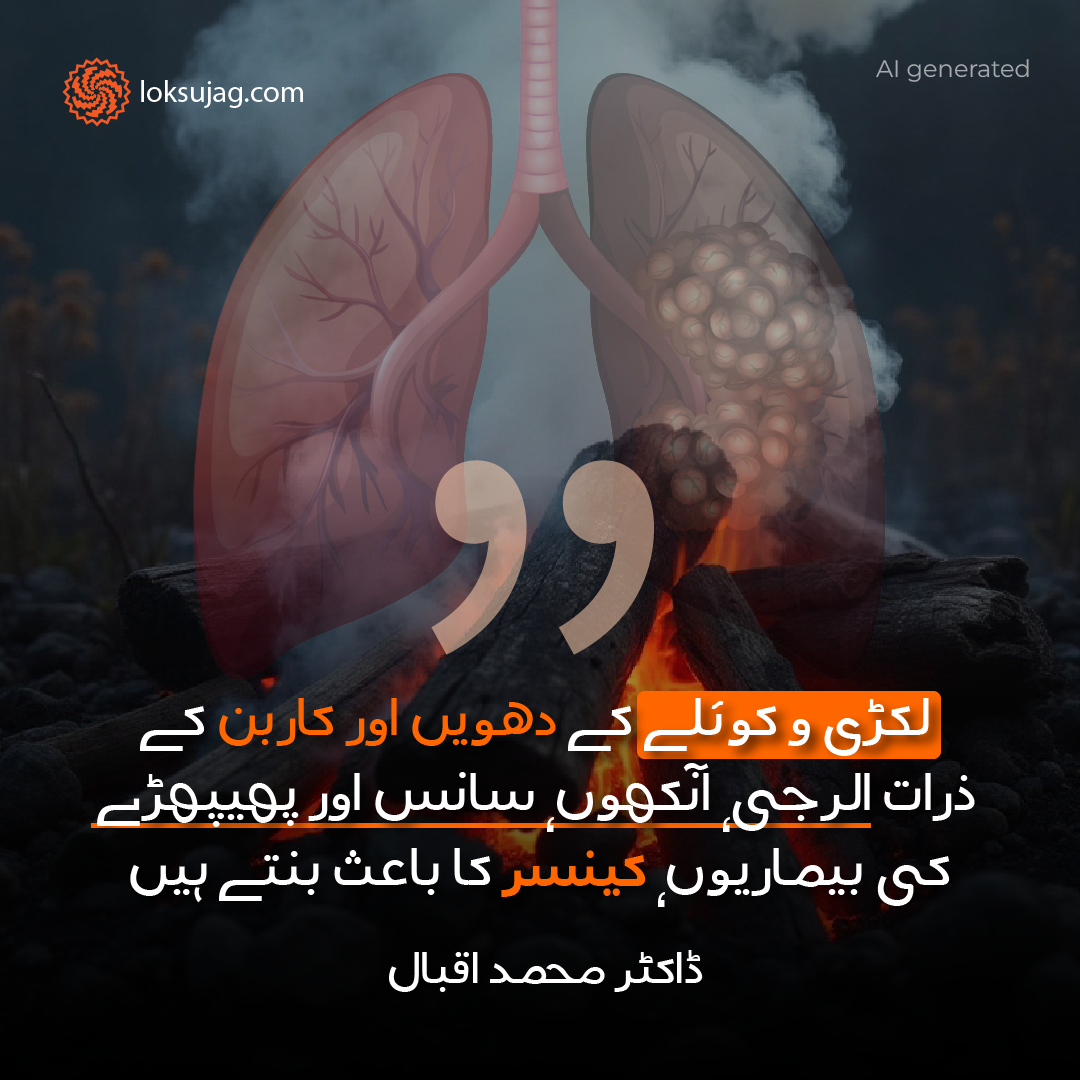
لکڑی جلانا انسانی صحت کے لیےخطرناک، آخر غریب کے لیے متبادل کیا ہے؟
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں لکڑیاں جلانا انسانی صحت خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔
فزیشن ڈاکٹر محمد اقبال بتاتے ہیں کہ کھانا بنانے کے دوران لکڑی و کوئلے سے اٹھنے والا زہریلا دھواں اور کاربن کے ذرات ہر عمر کے لوگوں میں الرجی، سانس اور پھیپھڑے کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ آگ کی تپش عورتوں کے بازو و چہرے کی جلد کو شدید نقصان پہنچاتی ہے جبکہ دھوئیں کے علاوہ شعاعیں (ریڈی ایشنز) آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں۔ بعض صورتوں میں کاربن کے ذرات دل کی بیماری اور پھیپھڑے کے کینسر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔
ڈاکٹر اقبال کے بقول گھریلو ایندھن کے لیے لکڑی کی بجائے گیس کا استعمال بہتر ہے۔
لیکن باجوڑ سمیت قبائلی اضلاع کے دیہات میں زیادہ تر لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے لیے قدرتی گیس تک رسائی اور ایل پی جی کے اخراجات برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔
اس صورت حال کے پیش نظر دیہی آبادی کے لیے بظاہر لکڑی کا کوئی متبادل نہیں جو انہیں پہاڑوں و جنگلات سے مفت میسر آجاتی ہے۔
تاہم انرجی ماہرین کہتے ہیں کہ لکڑی کا متبادل نہ ہونے کی بات سچ نہیں ہے، قدرتی گیس اور گرڈ کی بجلی ضرور مہنگی ہے مگر بائیوگیس اور سولر توانائی دونوں ابتدائی خرچے کے بعد مفت حاصل کی جا سکتی ہیں بشرطیکہ آپ پیدا کرنے والے بنیں۔ جن گھروں میں دوچار جانور موجود ہیں وہ ان کا ویسٹ (گوبر) استعمال کر کے مفت بائیوگیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قبائلی اضلاع میں کچھ کام ہوا بھی ہے۔

قبائلی اضلاع میں اب تک 300 بائیو گیس پلانٹس لگ چکے ہیں
پاکستان میں بائیو(گوبر) گیس کی پیداوار کا آغاز ویسے تو 20 ویں صدی کے دوسرے نصف میں ہوا جب 1959ء میں ٹنڈو جام (سندھ) میں پہلا بائیو گیس پلانٹ لگایا گیا۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں 70ء کے عشرے میں پلانٹس لگانے کی کوششیں کی گئیں۔
سمال انڈسٹریز ڈیویلپمنٹ بورڈ خیبر پختونخوا نے 2011ء میں بھی 400 بائیوگیس پلانٹس لگانے کا منصوبہ بنایا مگر پسماندہ ٹیکنالوجی اور کمیونٹی میں عدم آگاہی کے باعث یہ بیل منڈھے نہ چڑھ سکی۔
تاہم صوبائی حکومت نے2017 میں 'اپ لفٹنگ دی سوشو اکنامک کنڈیشن اینڈ جینڈر مین سٹریمنگ آف لائیوسٹاک ان فاٹا' کے نام سے ایک منصوبے کی منظوری دی جو محکمہ لائیوسٹاک نے تجویز کیا تھا۔
اس پراجیکٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد کامران بتاتے ہیں کہ وہ 2017 میں دو ماہ کے لیے جاپان گئے تھے جہاں جانوروں کے گوبر سے کمرشل لیول پر گیس پیدا کی جا رہی تھی۔ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ(پی اینڈ ڈی) کی منظوری کے بعد اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا جس کے لیے ابتدائی طور پر چار کروڑ رکھے گئے۔
وہ کہتے ہیں کہ یہاں اکثر گھروں میں تین چار گائے یا بھینسیں موجود ہوتی ہیں اس لیے گھریلو سطح سے کام کا آغاز کیا گیا۔ اس کا مقصد گوبر (ویسٹ) منیجمینٹ، کاربن کے اخراج پر کنٹرول اور قابل تجدید توانائی کا حصول تھا۔
"ہماری (حکومت کی) سوچ یہ تھی کہ اس منصوبے کا زیادہ فائدہ خواتین کو ہوگا ان پر کام کا بوجھ کم ہوگا اور لکڑی جلانے کے لیے درختوں کی کٹائی میں بھی کمی آئے گی۔"
ڈائریکٹر کی مطابق پہلے مرحلے میں باجوڑ اور مہمند میں 150 بائیوگیس پلانٹس لگائے گئے، بعد ازاں اس منصوبے میں ایف آر کوہاٹ، کرم اور دیگر علاقوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یوں 2022ء تک سرکاری سطح پر قبائلی اضلاع میں لگ بھگ 300 بائیو پلانٹس لگائے گئے۔

گھریلو بائیو پلانٹ کے اخراجات اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟
ڈاکٹر محمد کامران بتاتے ہیں کہ فاٹا اپ لفٹنگ پراجیکٹ کے تحت انہوں نے جتنے بھی پلانٹ لگائے ان پر فی پلانٹ اوسطاً ایک لاکھ 70 ہزار روپے خرچ آئے۔ تاہم کسی بھی گھرانے سے کوئی رقم وصول نہیں کی گئی اور یہ تمام سرکاری خزانے سے لگا کر دیے گئے۔
انہوں نے بتایا کہ بائیو گیس کے لیے پہلے فلوٹنگ ڈرم زمین میں نصب کیے جاتے، ان میں گوبر ڈال دیا جاتا تھا جس سے گیس پیدا ہوتی تھی۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ پیش آیا کہ ڈرم زنگ آلود ہو کر لیک ہوتے تو وہاں اکثر دھماکا ہو جاتا تھا۔
پھر نیپال میں اینٹوں اور کنکریٹ کے ڈرم بنانے کی ٹیکنالوجی (یا طریقہ کار) متعارف کرائی گئی۔ اب یہاں بھی زمین میں آٹھ سے دس کیوبک فٹ (226 سے 283 لٹر) کا گول ڈرم یاحوض تعمیر کیا جاتا ہے اور اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے۔
ڈرم میں 24 گھنٹے کے اندر فرمینٹیشن (گلنے سڑنے کا عمل) سے گیس بننا شروع ہوجاتی ہے جو پائپ کے ذریعے 60 سے 70 فٹ دور موجود کچن میں پہنچائی جاتی ہے۔ اب گیس لیک نہیں ہوتی، یہ تجربہ زیادہ کامیاب رہا۔
ڈائریکٹر کے مطابق ایک گائے 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ 20 کلوگرام گوبر دیتی ہیں جبکہ پلانٹ کو فعال رکھنے کے لیے روزانہ 40 کلوگرام ویسٹ چاہیے ہوتا ہے۔
یوں آٹھ سے 12 افراد پر مشتمل خاندان جس کے پاس کم از کم تین گائے موجود ہوں وہ گھر میں بائیو گیس پلانٹ آسانی سے لگا سکتا ہے۔ اس سے روزانہ ایک کلو گیس ملے گی جو تمام گھریلو ضروریات کے لیے کافی ہے۔

70 فیصد پلانٹس کامیابی سے چل رہے ہیں تو 30 فیصد غیرفعال کیوں؟
انٹرنیشنل جرنل آف انجنیئرنگ ورکس میں 2019ء میں شائع شدہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں نجی، سرکاری اور غیرکاری تنظیموں کے سرمائے سے لگائے جانے والے بائیو گیس پلانٹس میں سے تقریباً 27 فیصد بند پائے گئے جبکہ 73 فیصد کامیابی سے چل رہے تھے۔
بعد ازاں 2022ء میں ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور اور محکمہ لائیو سٹاک کی مشترکہ سٹڈی میں بھی لگ بھگ 30 فیصد پلانٹس غیرفعال ہونے کی تصدیق ہوئی۔
پراجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کی کوشش تھی کہ صرف مطلوبہ معیار پر پورا اترتے والے خاندانوں ہی کو پلانٹس دیے جائیں۔ لیکن سیاسی مداخلت پر کچھ ایسے گھروں میں پلانٹس لگائے گئے جہاں محکمہ مطمئن نہیں تھا وہ پلانٹ آج غیرفعال پڑے ہیں۔
دوسرے کچھ لوگ پلانٹس میں گوبر برقت نہیں ڈالتے۔ ضروری ہے کہ پلانٹ کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر فیڈ کیا ( گوبر ڈالا) جائے۔ اگر دو دن کا وقفہ ہو جائے تو گیس نہیں بنتی اور پورا ڈرم خالی کرنا پڑتا ہے جو زمیندار نہیں کرتے۔ یعنی زمیندار یا مالک کی سستی اور عدم دلچسپی پلانٹ کو غیرفعال کر دیتی ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ یہ پلانٹس لگانے کے عمل میں مقامی کاریگروں کو شامل کیا جائے تاکہ ٹیکنالوجی مقامی سطح پر منتقل ہو، لوگ اپنے گھروں میں پلانٹس لگائیں اور تکنیکی خرابی کی صورت میں خود ہی ٹھیک کریں۔
"ہمارا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا، غربت میں کمی اور جنگلات و ماحول کا تحفظ بھی تھا مگر اس طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ الٹا ہم سے نوکری مانگنے آ جاتے تھے۔"
اگرچہ قبائلی اضلاع میں سرکاری کے علاوہ مقامی لوگوں نے ذاتی سرمائے سے بھی نجی بائیو گیس پلانٹس لگائے ہیں مگر ابھی تک متبادل توانائی کا یہ ذریعہ زیادہ فروغ نہیں پا سکا۔
یہ بھی پڑھیں

بلوچستان: دیسی بائیو گیس پلانٹ ضرورت کے ساتھ منافع بھی
توانائی کا سستا ذریعہ، مگر گائے بھینسیں کم ہوتی جا رہی ہیں
بائیو گیس سے صرف خواتین ہی نہیں ککنگ سے وابستہ مرد بھی بھرپور استفادہ کررہے ہیں۔ تحصیل ماموند کے رہائشی فضل حق پچھلے 10 سال سے باجوڑ کے ایک ڈیری فارم میں بطور کک ملازمت کر رہے ہیں۔
وہ بتاتے ہیں کہ وہ چند سال پہلے تک گیس سلنڈر پر کھانا بناتے تھے۔ ہفتے میں چار سے پانچ کلو گیس استعمال کرتے تھے جو بہت مہنگی پڑتی تھی۔ بعض اوقات اچانک گیس ختم ہوتی انہیں کئی کلومیٹر سفر کر کے گیس لینے بازار جانا پڑتا تھا۔
"جب سے فارم پر بائیو گیس پلانٹ لگا ہے، 24 گھنٹے گیس میسر ہے۔ یہ توانائی کا بہترین اور سستا ذریعہ ہے، بٹن کھولو کھانا بنانے کے علاوہ وضو، غسل یا برتن دھونے کے لیے پانی گرم کر لو۔ یہ گیس ہم 30 ملازمین کے لیے سردی گرمی میں کافی ہو جاتی ہے۔"
ڈیری فارم کے منیجر ڈاکٹر رحمت شاہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں تین بائیو گیس پلانٹس ہیں اور تینوں فعال ہیں۔ ضرورت پڑے تو بائیو گیس سے جنریٹر بھی چلایا جا سکتا ہے، بس یہ سٹور نہیں ہو سکتی۔
وہ سمجھتے ہیں کہ بائیو گیس پلانٹس میں لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہیں مگر ماضی کے مقابلے میں اب گھروں میں گائے اور بھینسیں کم ہوتی جا رہی ہیں جس سے گوبر کی دستیابی کم ہو گئی ہے۔ یہاں لوگوں کی اکثریت کے پاس پلانٹ لگانے کے وسائل بھی نہیں ہیں۔
ان کا خیال ہے کہ باجوڑ میں 30 سے زیادہ ڈیری فارمز ہیں، اگر حکومت تعاون کرے تو یہاں بیشتر بے وسیلہ لوگوں کو بائیو گیس فراہم کی جا سکتی ہے۔
" ان ڈیری فارمز پر بڑے بائیو گیس پلانٹس لگا دیے جائیں تو پائپ لائنوں کے ذریعے ارد گرد کے گھروں میں سپلائی دی جا سکتی ہے۔ اس طرح یہاں ماحول اور قدرتی جنگلات کو بچانے میں مدد مل سکتی ہے ورنہ درختوں کی کٹائی نہیں رکے گی "
تاریخ اشاعت 29 اپریل 2025